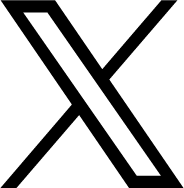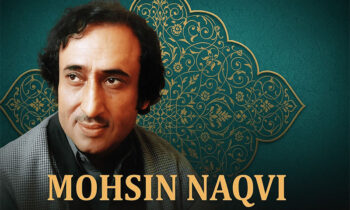صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل کو دیا جانے والا استثناء تو ہر طرف زیر بحث ہے، سوال یہ ہے، کیا عدلیہ کو حاصل غیر تحریری تاحیات استثناء پر بھی کبھی کوئی بات ہو گی؟
سیاست دان تو جنم جنم سے قانون کا سامنا کر رہے ہیں، وزیر اعظم کسی بھی جماعت کا ہو، ایوان اقتدار سے نکلنے کے بعد اس کا ’نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ‘ ہی ہوتا ہے۔
اسی طرح جرنیل بھی کسی نہ کسی درجے میں قانون کا سامنا کرتے ہی ہیں۔ ایک مثال پرویز مشرف ہیں اور دوسری فیض حمید ہیں ، بیچ میں میجر جنرل ظہیر الااسلام عباسی سے لے کر ایڈمرل منصور منصور الحق تک کئی نام پیش کیے جا سکتے ہیں جنہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔
ملک میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو یا بائیں ہاتھ میں، قانون کی جرات نہیں کہ وہ اس کی دہلیز پر دستک دے سکے۔ یہ ہماری عدلیہ ہے۔ ایک طالب علم کے طور پر سوال وہی ہے کہ کیا جج حضرات کو بھی تاحیات استثنا حاصل ہے؟
اس بات کو چند سادہ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔
پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت آئین شکنی کا مقدمہ قائم ہوا اور پھر سزا سنا دی گئی لیکن آرٹیکل 6 میں تو یہ بھی لکھا ہوا صرف آئین شکنی کا ارتکاب کرنے والے کو ہی سزا نہیں ہو گی بلکہ جو اس میں مدد دے، ساتھ دے، اکسائے یا ترغیب دے اس کو بھی سزا ہو گی۔ اب سوال یہ ہے کہ پرویز مشرف کو تو سزا سنا دی گئی لیکن سپریم کورٹ کے ان ججوں کا کیا ہوا جنہوں نے پرویز مشرف کے اقدام کی نہ صرف توثیق کی بلکہ انہیں آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ کیا یہ بھی برابر کے مجرم نہیں تھے؟
آئین میں ترمیم کا ایک ہی طریق کار ہے اور وہ ہے دو تہائی اکثریت کے ساتھ پارلیمان کا فیصلہ، آئین میں تبدیلی کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں بھلے فل بنچ ہی بیٹھ جائے۔ لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ قانون نے آج تک ان جج صاحبان سے کیوں نہیں ہوچھا کہ جناب آپ خود آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، ذرا کٹہرے میں تشریف لائیے۔
پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 6 میں ایک ترمیم کی اور لکھا کہ سنگین غداری کے کام کو سپریم کورٹ یا ہائیکورٹ کے ذریعے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کا اطلاق آنے والے وقت میں ہو گا لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 12 کی ذیلی دفعہ میں واضح ہے کہ آرٹیکل 2 میں جب بھی کوئی ترمیم ہو گی یا اس کا اطلاق ہو گا تو یہ 23 مارچ 1956 سے ہو گا۔ یعنی اس کا رٹراسپکٹو ایفیکٹ ہو گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 مارچ 1956 سے اب تک عدالتوں نے جتنے مارشل لاؤں کی توثیق دی وہ جرم ہے۔ پارلیمان کی توثیق کے باوجود جرم ہے۔ اس جرم پر قانون کیوں نہیں لاگو ہو رہا؟ اس سوال پر سوچتے رہیے اور محسوس کیجیے کہ یہ غیر تحریری استثنا کتنا طاقت ور ہے۔
پاکستان میں نظریہ ضرورت متعارف کرنے والی بھی سپریم کورٹ ٰ (فیڈرل کورٹ ) تھی۔ چیف جسٹس منیر نے نہ صرف غیر آئینی اقدام کی توثیق کی بلکہ فیصلے میں لکھا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ لکھا کہ پاکستان کی پارلیمان کی برطانوی سرکار کے علامتی نمائندے یعنی گورنر جنرل غلام محمد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اور جب تک وہ توثیق نہ کر دیں پارلیمان کے بنائے قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ ( دل چسپ بات یہ ہے کہ جسٹس منیر کا یہ شرمناک فیصلہ قائد اعظم کی قائم کر دہ پارلیمانی روایت سے بھی انحراف تھا ) ۔ سوال یہ ہے کہ آج تک جسٹس منیر کے خلاف کوئی علامتی کارروائی ہو سکی؟ کارروائی تو دور کی بات ہے ان صاحب اور مارشل لاؤں کی توثیق کرنے والے دیگر تمام مائی لارڈز کی تصاویر سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمر ون میں آویزاں ہیں۔
بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ یہ سوال آج تک موجود ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے یعنی عدالتی قتل کرنے والوں کے خلاف کوئی علامتی کارروائی آج تک کیوں نہ سکی؟ ان کی تصاویر ہی کم از کم کورٹ روم نمبر ون سے ہٹا دی جاتیں۔
کرپشن کے مقدمات میں سب کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ اہتمام مگر صرف عدلیہ کے لیے ہے کہ عدالت کے کسی معزز جج کی کرپشن، بد عنوانی کے ثبوت آ جائیں تو کارروائی سے پہلے انہیں یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ چاہیں تو کارروائی کا سامنا کریں اور چاہیں تو استعفی دے کر گھر چلے جائیں، پنشن سے لطف اندوز ہوں اور مراعات سے جی بہلائیں۔ الزام جب نوشتہ دیوار بن جائے تو کتنے ہی جج استعفی دے کر گھر چلے جاتے ہیں اور غریب قوم انہیں ساری عمر پنشن اور مراعات دیتی رہتی ہے۔ کوئی ہے جو سوال کرے کہ کیوں؟
ہر شعبے میں سوال اٹھتے ہیں، ہر ایک سے کسی نہ درجے میں سوال ہوتا ہے، یہ صرف عدلیہ ہے جس کی کارکردگی کو زیر بحث لانے کی جرات خود پارلیمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس کی کارکردگی اور مراعات کے تناسب پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھتی۔ ریکو ڈک کا ایک کیس فیصلہ پاکستان کو 6 ارب ڈالر میں پڑتا ہے لیکن کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔
آئین میں لکھا ہے کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی لیکن یہاں ہو جاتی ہے اور پارلیمان کو اس بند گلی میں لایا جاتا ہے جہاں یا تو ساری ترمیم اڑا دی جائے گی یا ججوں کی تعیناتی کے چیف جسٹس کے اختیارات کو نہ چھیڑا جائے۔ ذرا یاد تو کیجیے افتخار چودھری صاحب کے دور میں 18 ویں ترمیم کے وقت پارلیمان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟
لیکن ہم دیکھتے ہیں عدالتیں آئینی پابندی کے باوجود آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سن لیتی ہیں، آئین کی تشریح کے نام پر آئین کو ری رائٹ کر دیا جاتا ہے لیکن نہ کسی حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی جرات ہوتی ہے نہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی۔
کرکٹ بورڈ سے وی آئی پی پاس مانگ لیے جاتے ہیں تو کبھی ایئر پورٹ اتھارٹیز کو پروٹوکول کے لیے خط جاتے ہیں لیکن آج تک کوئی نہیں پوچھ پایا کہ کیا یہ سب کچھ عدالت کے لیے طے کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں؟
اراکین پارلیمان کی کارکردگی کو عوام جانچتے ہیں اور قانون تو اکثر ہی جانچتا رہتا ہے، افسران سول کے ہوں یا ملٹری کے ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بھی جانچنے کا باقاعدہ میکنزم ہے لیکن عدلیہ کے لیے ایسا کچھ نہیں۔ کوئی ایسا میکنزم نہیں جو پرکھ سکے کہ کس جج نے کتنے عرصے میں کتنے فیصلے کیے اور ان میں سے کتنے فیصلے آگے چل کر اپیل میں کالعدم ہو گئے اور کس نے سماعت اوسطاً کتنے عرصے میں مکمل کی اور کس نے سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ لکھنے میں 223 دن لگا دیے۔
یہاں مکمل استثنا کی کیفیت ہے اور تاحیات ہے۔ اس پر اضافی لطف یہ کہ غیر تحریری ہے اس لیے کہیں زیر بحث بھی نہیں ہے۔ بیچ میں کہیں اصلاح احوال کی صورت پیدا ہونے لگے تو بار ایسوسی ایشنز کے ہمارے پیارے پیارے دوست عہدیداران میدان میں آجاتے ہیں کہ خبردار ! عدلیہ کی آزادی خطرے میں ہے۔ ان کے خیال میں اسلام آباد کی پولن الرجی کی طرح یہ بھی ایک تاحیات قسم کا خطرہ ہے۔
یہاں آ کر مجھے نو آبادیاتی دور کے پینڈرل مون یادآ جاتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں یاد آ جاتے ہیں تو میں یہ نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے لیے آپ کو ان کی کتاب ’سٹرینجر ان انڈیا‘ پڑھنا پڑے گی۔
ادارے کا کالم نگار کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔