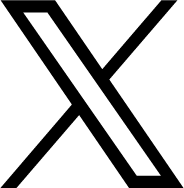’یہ 20 فروری 1994 بمطابق 9 رمضان المبارک 1414 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کے دوسرے دور حکومت کا زمانہ تھا جب 3 افغانی دہشتگرد پشاور ماڈل اسکول کی ایک بس کو اغوا کرکے اُسے اسلام آباد میں افغانستان کے سفارتخانے تک لے آئے۔ بس میں 70 بچے اور 7 ٹیچر تھے۔ حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ تھا۔
دہشتگردوں کے پاس لوڈڈ پسٹل تھے اور وہ اپنے مطالبات کی خاطر کچھ بھی کرسکتے تھے۔ حکومت کے کارندوں کو اُن کے ساتھ بات چیت کرنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی اس لیے کہ وہ فارسی بولتے تھے اور ہمارے اہلکار کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے انھیں مصروف رکھنا چاہتے تھے۔
سحری کا وقت قریب تھا۔ اچانک میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک سرکاری اہلکار جو مجھے اچھی طرح جانتے تھے کہ میں فارسی کا پروفیسر ہوں، اُنھوں نے مجھے بتلایا کہ یہ مسئلہ در پیش ہے۔ میں بے درنگ اُن کے ساتھ ہولیا۔
افغان سفارتخانے پہنچتے ہی مجھے ایک بہت بڑے کمرے میں داخل کردیا گیا جہاں پر سارے اغوا شدگان بڑے سہمے ہوئے اور گم صم حالت میں تھے۔ اور ان کے آگے تینوں دہشتگرد پستول تانے ہوئے بالکل الرٹ بیٹھے تھے۔ یہ پر خطر منظر دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا کیا بات کروں؟ بہر حال میں نے اُنھیں بتلایا کہ میں فارسی کا اُستاد ہوں ۔ اُن میں سے ایک کہنے لگا:
’ماخیلی احترام میگزاریم به استاد‘
(ہم اُستاد کی بہت عزت کرتے ہیں)
میں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے پوچھا:
اسلام آباد زیادہ سرد ہے کہ کابل؟
انھوں نے جواب دیا:
کابل زیادہ سرد ہے۔
مجھے اُن کے سامنے قطعاً کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد (جو مجھے اب یاد نہیں) میں اپنی مرضی سے اس کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر کچھ وقفے کے بعد میں نے 3 دفعہ ٹھاہ۔۔۔ ٹھاہ۔۔۔ ٹھاہ۔۔۔ کی آواز سنی۔ تینوں دہشتگردوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔
مزید پڑھیں: ہمارے انورؔ مسعود
مجھے ایک دم بڑے خوف نے آلیا کہ میں کتنی مخدوش اور پُرہول صورتحال میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے اُس وقت فارسی کا غالب کا مصرع یاد آیا جو بڑی باریک انسانی نفسیات کا انکشاف کر رہا ہے:
’بے تکلف در بلا بودن بہ از بیم بلاست‘
یعنی مصیبت میں مبتلا ہو جانا مصیبت کے خوف میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔
مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ دہشتگرد پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بند ہونے پر احتجاج کررہے تھے۔ اس لیے کہ اُن کے لیے کھانے پینے کی اشیا کی ترسیل رک گئی تھی اور اس کے بدلے میں وہ تاوان مانگ رہے تھے اور اُن کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ افغانستان واپس جانے کے لیے انھیں ہیلی کاپٹر بھی فراہم کیا جائے۔ اس آپریشن کی نگرانی وفاقی وزیرداخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر کر رہے تھے۔‘

’مُجھے سَب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو‘ (حکیم مومن خان مومن)
آج ہی کے دن (20 فروی) 32 برس قبل (1994) پیش آنے والا یہ خوفناک واقعہ شاعرِ بے بدل انور مسعود کی یادداشتوں کی کتاب ’مجھے سَب ہے یاد ذرا ذرا‘ میں درج ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک شاعر کی داخلی قوت کا اظہار بھی ہے جو خوف کو لفظوں کی تہذیب سے شکست دیتا ہے۔
کچھ لوگ وقت کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کچھ وقت کو لفظوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اردو اور پنجابی کے ممتاز شاعر انور مسعود نے اپنی یادداشتوں کی کتاب ’مُجھے سَب ہے یاد ذرا ذرا‘ میں یہی کام کیا ہے۔ جنوری 2026 میں منصہ شہود پر آنے والی اس کتاب کو ’بک کارنر جہلم‘ نے شائع کیا ہے۔ یہ محض یادوں کا مجموعہ نہیں، ایک پورا عہد ہے جو لفظوں کے دریچوں سے جھانکتا ہے۔
لفظوں میں بسی صدی کی خوشبو ’مُجھے سَب ہے یاد ذرا ذرا‘ نہ صرف یادداشتیں ہیں بلکہ یہ ادب، شاعری، اور انسانی جذبات کا حسین امتزاج بھی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ادب کو زندگی کے تجربات سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہر لمحے کی خوشبو اور رنگ کو لفظوں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں۔انور مسعود نے یادوں کو محفوظ نہیں کیا، انہیں زندہ رکھا ہے۔ اور یہی بڑے تخلیق کار کے فن کی معراج ہے۔
’مُجھے سَب ہے یاد ذرا ذرا‘ کا ہر صفحہ قاری کو مسکرانے، دل سے محسوس کرنے، اور کبھی کبھی آنسو چھپانے کا موقع بھی دیتا ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے ایک شفیق استاد، ایک بذلہ سنج بزرگ اور ایک گہری نظر رکھنے والا شاعر ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اور کہہ رہا ہے: آؤ، تمہیں کچھ قصّے سناؤں۔
اگر میں برف خرید نے نہ جاتا؟
میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ایک شعر کو احمد ندیم قاسمی نے 2 مرتبہ اپنے کالم میں سراہا۔ کئی اور مشاہیر شعرا نے اسے قابل تحسین گردانا ہے۔ شعر یوں ہے :
یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر
برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا
یہ شعر تخلیق کیسے ہوا تھا؟ میں لاہور کے علاقے سمن آباد میں اپنے سسر صاحب ( شفیق احمد صدیقی مرحوم ) کے ہاں قیام پذیر تھا۔ ایک دن میری خوشدامن صاحبہ نے مجھے کہا کہ بازار سے کچھ برف لے آؤ۔
گھر کے قریب ہی سڑک کنارے ایک برف فروش کی دکان تھی۔ اُس نے برف کے ڈھیر کو بوری سے ڈھانپ رکھا تھا۔ برف کی سل کو توڑنے کے لیے جب اُس نے سُوا مارا تو برف کا ایک ٹکڑا ترازو کے اُس پلڑے میں جا گرا جہاں لوہے کا باٹ پڑا تھا۔ اس منظر نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ لوہے کا باٹ تو میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پلڑے میں صرف برف کا باٹ رہ گیا۔
میرے تخیل نے اس منظر میں بڑھتی ہوئی بددیانتی کوبھی شامل کرلیا۔ کچھ دھوپ کی تمازت بھی جزو منظر ہو کر اس شعر کی تخلیق کا باعث بن گئی۔ اگر میں برف خرید نے نہ جاتا تو یہ شعر ہرگز وجود میں نہ آتا اور نہ اس شعر کی بنیاد پر اس زمین میں پوری غزل تخلیق ہوتی۔ اس واقعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاعری تجربے اور تخیل کے ملاپ کا نام ہے۔

حیرت انگیز واقعہ
ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ان دنوں گرمیوں کے دن تھے۔ مشاعرے کے دوسرے روز ظہر کے وقت میں اور کچھ دوست ایک کمرے میں محو استراحت تھے کہ اچانک میں نے اپنی اہلیہ (صدیقہ ) کی آواز سنی: ’انور صاحب!‘
يا للعجب! کہاں آسٹر یلیا اور کہاں پاکستان۔ میری بیگم تو اس وقت اسلام آباد میں تھیں اور میں سڈنی میں۔ اگر یہ آواز صرف میں نے سنی ہوتی تو اسے وہم و التباس بھی کہا جا سکتا تھا لیکن وہاں پر سب دوستوں نے کہا کہ آپ سے مخاطب ہوتی ہوئی یہ آواز ہم نے بھی سنی ہے۔
اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کا کوئی نا قابل فراموش واقعہ سناؤ تو اس سے زیادہ نادر الوقوع، تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس! کہ اتنی دور سے مجھے پکارنے والی آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے۔
وہ ترے نصیب کی بارشیں ۔ ۔ ۔
اللہ مغفرت فرمائے، امجد اسلام امجد میرا بہت ہی بے تکلف دوست تھا۔ پھر یہ دوستی عزیز داری میں بدل گئی۔ امجد کی بیٹی میری بہو اور امجد میرا سمدھی بن گیا۔ جن دنوں میں اسلام آباد کے سیکٹر آئی نائن میں مقیم تھا، امجد نے فون پر مجھے اسلام آباد آنے کی اطلاع دی۔ میں نے اُسے راضی کرلیا کہ سہ پہر کی چائے وہ میرے ساتھ پیے گا۔
چائے کی معاونت کے لیے میں ایک قریبی بیکری سے کئی ایک چیزیں لے آیا۔ میرے منجھلے بیٹے عمار مسعود کو اس کی بھنک پڑگئی، وہ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ بار بار ان چیزوں کی طرف لپکتا تھا۔ میں نے اُسے کئی دفعہ سمجھایا کہ بیٹے مہمان کو آ لینے دو۔ پھر جی بھر کے کھا لینا۔
لیکن اُس پر اس روک ٹوک کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اُن چیزوں پر بار بار حملہ آور ہوتا تھا۔ اتنے میں امجد کا فون آگیا کہ بھائی آج میرا آنا مشکل ہے۔ بڑی مصروفیت کا سامنا ہے۔ فون کی یہ کال عمار نے بھی سن لی۔ پھر تو وہ اُن چیزوں پر پل پڑا۔ کیک اور پیسٹری وغیرہ کھاتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ امجد کا مصرع بھی پڑھتا جاتا تھا:
’وہ ترے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں‘
’اج کیہ پکائیے‘
میرے ایک دوست رشید نوشاہی (مرحوم) تھے۔ بہت ہی زندہ دل شخصیت۔ لطیفوں اور مزاحیہ باتوں سے مالا مال۔ ایک مرتبہ اُنھوں نے مجھے ایک طویل لطیفہ سنایا جو ایک چوہدری اور اُن کے باورچی کا باہمی مکالمہ تھا۔ اس لطیفے کو میں نے کئی مہینوں کی محنت شاقہ سے شاعری میں ڈھالا ۔ میری اس نظم کا نام ’اج کیہ پکائیے‘ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عوامی موضوع پر لکھی ہوئی نظم کو غیر معمولی شہرت اور مقبولیت سے نوازا ہے۔ بیسیوں مشاعروں میں میں نے اس کی داد سمیٹی ہے۔ اسے Touch of the Artist کا ایک نمونہ کہہ لیجیے۔
میری شاہکار نظم دِینا
احمد ندیم قاسمی کی رائے میں میری شاہکار نظم ’دِینا‘ ہے۔ یہ جہلم سے قریب والا دینہ شہر نہیں ہے بلکہ ایک دین محمد ہے۔ محلے میں جس کی دودھ، دہی کی دکان تھی۔ بے چارا تپ دق کا مریض تھا۔ گاہک اس ڈر سے اُس سے دُور رہتے تھے کہ اس نامراد بیماری کے جراثیم کی زد میں نہ آجائیں۔ یہ اُسی بیمار دُکاندار کی داستانِ کرب ہے اور ایسے دُکانداروں سے ہماری گلیاں بھری پڑی ہیں۔
اوکھے ویلے نکھڑ جاندے سجن یار نگینے
ایہہ اک ایسی دنیا جتھے گلی گلی وچ دِینے
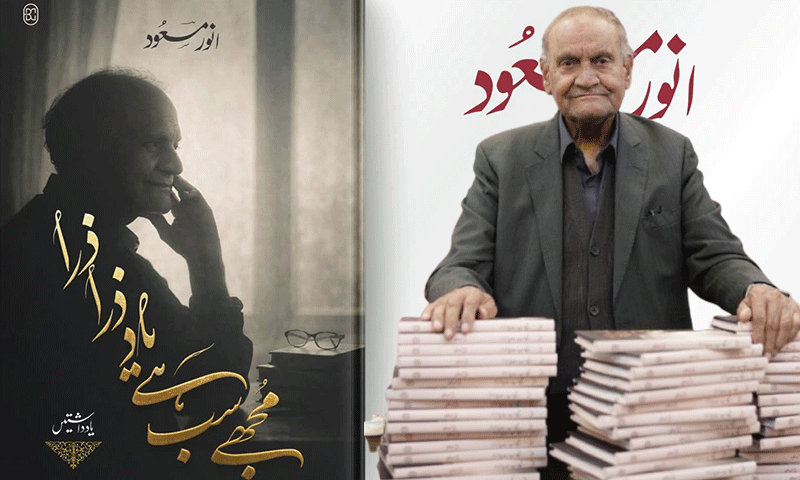
رکشے والا
مجھے کئی مرتبہ رکشوں میں سفر کرنے کا موقع ملا ہے۔ رات کو رکشا ڈرائیور اکیلے رکشا نہیں چلاتے۔ اُن کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہوتا ہے، سواری کو بٹھا کر وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات سواری بھی گفتگو میں شریک ہو جاتی ہے۔ پنجابی نظم ’رکشے والا‘ اسی تجربے کی روداد ہے۔ حالات حاضرہ پر عوامی تبصروں کا رواں تبصرہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عوامی مسائل عوامی زبان میں۔
ریشہ دوانیاں
1952 کا ایک یادگار واقعہ ہے جب میں میٹرک میں تھا۔ میرا ایک کلاس فیلو عبدالمجید تھا۔ ایک دن اپنے اسکول (پبلک ہائی اسکول) سے چھٹی کے بعد ہم گجرات کے مسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ عبدالمجید نے اچانک مجھ سے پوچھا، انور تمھارے پاس ایک دوانی (اس زمانے کا ایک سکہ) ہوگی، میں نے کیمسٹ سے ریشے کی دوائی لینی ہے۔ میں نے اُسے دوانی دیتے ہوئے صرف یہ کہا: ’مجید! اک تے سانوں تیریاں ایہہ ریشہ دوانیاں لے بیٹھیاں نئیں۔ (مجید! ایک تو ہمیں تیری یہ ریشہ دوانیاں لے بیٹھی ہیں)
گلفشانی
میں ابھی بی اے کا طالب علم تھا اور شاعر کی حیثیت سے شہر بھر ( گجرات) میں مشہور ہوچکا تھا۔ ایک دن ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مکان کی چھت پر سے کسی نے مجھ پر کچھ پھول پھینکے۔ پھولوں کے ساتھ ایک نسوانی آواز بھی سنائی دی: (Favourite Poet)
میں اُس دست گلفشاں کو دیکھ نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ جس شہر میں بجلی کے پنکھے بنتے ہیں وہاں پر کسی سیلنگ فین کا ہونا کچھ عجب نہیں۔ مہک اس واقعے کی آج بھی محسوس کرتا ہوں ۔
پسماندگانِ غزل
میانوالی میں ایک مشاعرہ ہورہا تھا۔ ایک شاعر غزل پڑھ رہے تھے اور ’غزل‘ ہی اُن کی ردیف تھی اور قافیہ تھا یعنی گلستانِ غزل، ارمغانِ غزل، کاروانِ غزل، داستانِ غزل، آسمانِ غزل، آشیانِ غزل … نہ قافیے ختم ہو ر ہے تھے نہ غزل۔
سید ضمیر جعفری صاحب بھی اس مشاعرے میں شریک تھے۔ قافیوں کی اس بھر مار اور بوچھاڑ سے گھبرا کر گویا ہوئے :
بھائی ہمارا بھی کچھ خیال کرو ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں ’پسماندگانِ غزل‘ یہ سن کر حاضرین کا قہقہہ فوارے کی طرح پھوٹ پڑا۔
مزید پڑھیں: 8 نومبر: یوم انور مسعود
ادبی زندگی کا نچوڑ
میری ادبی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ مشکل لکھنا بہت آسان ہے اور آسان لکھنا بہت مشکل۔ عمدہ شاعری وہ ہے جو دونوں کو رضامند کرے۔ ادب کا استاد بھی اُس کی داد دے اور چھابڑی والا سنے تو وہ بھی پھڑک جائے۔ جس میں فنی کمال و جمال بھی ہو اور ابلاغ کی وسعتیں بھی۔ یعنی ایسا لطف سخن جسے زیادہ سے زیادہ قبول خاطر نصیب ہو۔
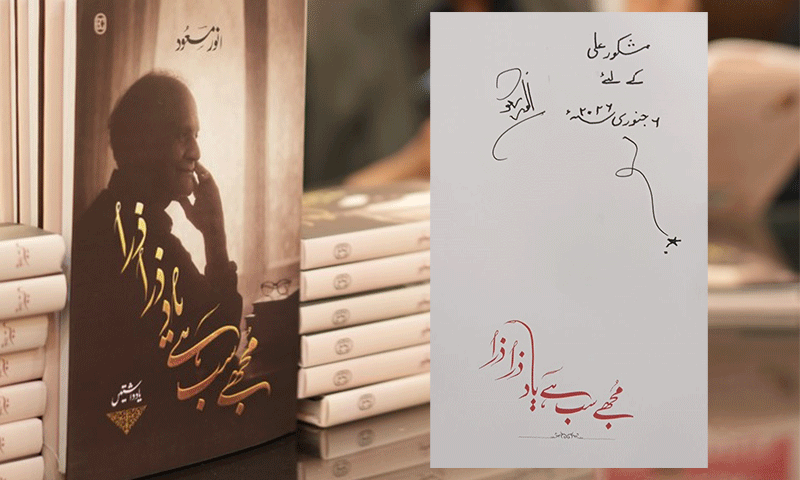
غیبی ہاتھ
بہت دنوں کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا، اتنا اندھیرا چھا چکا تھا کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہولی فیملی اسپتال (راولپنڈی) کے قریب سے ہوتا ہوا اس تاریکی میں سائیکل پر سوار تھا۔ اُسی سڑک پر ایک کار بھی رواں تھی اور کار کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھیں۔ نہ کار والے کو میری سائیکل دکھائی دے رہی تھی نہ مجھے اُس کی کار اور دونوں مخالف سمتوں سے ایک سیدھ میں آ رہے تھے۔
ایک نہ دکھائی دینے والی سائیکل ایک نہ دکھائی دینے والی کار کی زد پر تھی۔ میری سماعت نے تصدیق کی کہ جب کار میرے قریب پہنچنے والی تھی تو ایک نہ دکھائی دینے والے ہاتھ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں کار کی زد سے نکل گیا۔
اُس وقت کس غیبی ہاتھ نے میری جان بچائی مجھ پر یہ عقدہ آج تک نہیں کھل سکا۔ ماننا پڑے گا کہ وقت مقررہ سے پہلے آپ کو جان کی امان حاصل رہتی ہے۔
سید وزیرالحسن عابدی صاحب کے ملفوظات
مجھے یاد پڑتا ہے اُستاد گرامی سید وزیر الحسن عابدی کو رمضان میں وہ ہنسی بھی ناگوار گزرتی تھی جو قہقہے کی صورت اختیار کر جائے۔ کھل کر ہنسنے والے سے کہا کرتے تھے:
’یوں نہ ہنسیے، ماہِ مبارک ہے۔‘
ادارے کا کالم نگار کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔