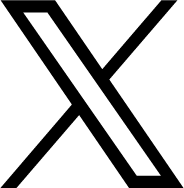2 دہائی قبل لکھنؤ کا ویزہ لگنے کے باوجود لکھنؤی تہذیب کو دیکھے بنا آجانا بدقسمتی نہیں تو اسے اور کیا کہیے؟ دلّی، آگرہ سے 6 گھنٹوں کا ہی تو فاصلہ تھا لیکن کم وقت میں کیا کیا دیکھیں؟، یہ الجھن پورے سفر میں ذہن پر غالب رہی۔ خیر اس وقت تو لکھنؤ جا پائے نہ اودھ سلطنت کے آخری فرماں روا واجد علی شاہ کے دور کی باقیات دیکھ سکے، لیکن پچھلے ہفتے بُک کارنر جہلم کی اشاعت شدہ 2کتابیں ’ دکھیارے‘ اور’ ہیچ ‘ پورا لکھنؤ سمیٹ کر گھر کے دروازے پر آن وارد ہوئیں۔
سونے پر سہاگہ بُک کارنر جہلم کی کتابت، چھپائی اور سرورق کے کیا ہی کہنے۔
محترم انیس اشفاق لکھنؤ کے وہ ادیب ہیں، جنہوں نے اپنی تحریروں میں اس شہر، اس کی تہذیب اور دم توڑتی روایتوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ قاری کو سُبک روی سے لکھنؤ کی گلیوں، محلّوں، کوٹھیوں، محل سراؤں، غلام گردشوں، کربلاؤں، امام باڑوں اور ان سے متصل صحنچیوں اور ان میں بسنے والے انسانوں کے عین درمیان لا پہنچاتا ہے….. یہاں قاری خود کہانی کے کرداروں میں ڈھل کر آس پاس کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے۔
مختصر ناول ’دکھیارے‘ میں ……لکھنؤ اور وہاں بسنے والوں کے حالات کا نوحہ ذاکر کی زبانی ہے….جس کی ماں اپنے بڑے بیٹے کے دماغی خلل کے باعث اپنے جان لیوا مرض کو پس پشت ڈال کر اسی شش وپنج میں رہی کہ مرنے کے بعد کون بڑے بیٹے کی دیکھ بھال کرے گا۔
بڑے بھیّا کا کردار پورے ناول میں حاوی رہا، خصوصاً ذاکر کو لکھے ان کے خطوط ہوں یا بات چیت، اس میں پاگل پن بھی ہے اور بلا کی معصومیت بھی۔
’ پرسوں ماں سے ملاقات ہوئی تھی ..
ماں تو کب کی مر چکی…. ذاکر بولا
کب؟ وہ اچھل پڑے …جھوٹے…پرسوں ہم نے بہت دیر باتیں کیں ‘
منجھلا بھائی حساسیت سے پرے کاروبار زندگی میں مصروف رہا۔
3 بیٹوں کی ماں؛ …..عالیہ بیگم عرف علّن باجی جو لال اسکول میں دکان کیا کرتی تھیں۔
بڑے بھیّا جو دماغی خلل کے باعث عجب سودائی شخص، ایک جگہ ٹک کر رہنا ان کی فطرت میں نہ تھا۔
’منجھلے سے ہوشیار رہو، موسیٰ باغ میں ایک مکان دیکھا ہے وہاں مل کر رہیں گے، ماں کو بھی ساتھ رکھیں گے۔‘
’ اب مجھے تلاش مت کرنا گھنٹا گھر کی نیلامی ہونے والی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کر رہاہوں۔ اس کے بعد شیش محل بھی خریدنے کا ارادہ ہے۔
اور ہاں لڈن کی چکی پر میرے لیے کچھ پیسے رکھوانا مت بھولنا۔ دَم والی چائے بنا دی ہے اٹھ کر پی لینا۔
ہر بار کچھ روز ذاکر کے پاس گزار کر اچانک بڑے بھیّا ایک چِھٹی چھوڑ کر ہوا ہو جاتے۔
ماں کی قبر کو پکا کرنا ہو یا کتبا بنوانا ہو سب ذاکر کی ذمہ داری تھی۔
ناول میں اجڑتے گھرانوں کے قصے، ٹھنڈی سڑک اور صحنچیوں کے کھینچے گئے نقشے نے حیدرآباد سندھ کے پرانے شیعہ محلّوں کی یاد تازہ کردی۔ میر انیس کے مقبرے کے ساتھ خواجہ کی حویلی بک رہی ہے۔ جہاں ماں کی دوستیں بدر جہاں اور بانو ایک بوسیدہ اور میل زدہ کمرے میں سامان کی بندھی بکھری پوٹلیوں کے درمیان صرف 2 پوٹلیاں ہی نظر آتی ہیں۔
سوکھے پڑے حوض اور فوارے …منہدم ہوتی حویلی کی منظر کشی ایسی کہ قاری بھی اپنے اندر سناٹا اترتا ہوا محسوس کرے۔
اس مختصر ناول میں تقسیم کے دُکھ کے بعد لکھنؤ میں یکے بعد دیگرے برپا ہونے والے شیعہ سنی فسادات کا ماتم ہے…. جس میں کبھی بڑے بھیّا کا جسم گھائل ہوتا ہے اور کبھی ذاکر کی روح۔
آبائی گھر کے قرق ہونے پر ماں کی تہی دامنی بڑے بھیّا کے خلل والے دماغ سے کبھی نکل نہ پائی تھی۔
’ماں کو دیکھے کئی دن ہوئے اسے ہی ڈھونڈنے نکلا ہوں، شیش محل سے آگے زمین پر ایک بڑی حویلی بنوانے کا ارادہ ہے جس میں ماں کے لیے ایک امام باڑہ بھی ہوگاجہاں وہ عزاداری کریں گی۔‘
لیکن انہیں سب بکھیڑوں میں بچپن کی دوست سائرہ کی یاد دل میں کچوکے لگاتی تھی تو دوسری جانب بڑے بھیّا کے نت نئے ٹھکانے بدلنا ذاکر کو سب کے سامنے شرمندہ بھی کرتا تھا …..
اور پھر ایک کربلا میں بھیّا کا ٹھکانہ ذاکر کے دل کو بھی بھا گیا۔
کربلا کی ایک صحنچی میں سینی میں پروسی روغنی روٹیاں، بھنڈی کی سبزی، دُھلی ماش کی دال …. جسے بڑے بھیّا اور ذاکر شوق سے کھا رہے ہیں۔
اور ٹاٹ کے پردے سے جھانکتی ہوئی شمامہ ….
ناول میں شمامہ اور بڑے بھیّا جیتے جاگتے کردار ہیں۔
ناول میں کوئی کردار بلاوجہ نہیں، چاہے وہ بڑے بھیّا کی بگڑتی صحت پر فکرمند دارُلشفا کے حکیم صاحب ہوں یا بھیّا کی سنگت سے لطف اندوز ہوتے آغا سودائی….
کہانی قاری کو لکھنؤ کی بکھرتی ہوئی تہذیب سے روشناس کرواتے ہوئے ذاکر کے کمرے پر ختم ہوتی ہے جہاں اس کے لیے شمامہ کی ہاتھ کی کڑھائی والا کرتا پڑا ہوا ہے۔
ہیچ ….. یہاں مصنف کا قلم قرطاس پر لکھنؤ کے پرانے محلے بنجاری ٹولہ کی کہانی بیان کرتا ہے جہاں تقسیم نے اپنوں کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ کوئی لکیر کے اُس پار جارہا ہے تو کوئی لکیر عبور کرنے کا ذکر تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ دراصل ہم بن پروں والوں کے لیے زمینیں زنجیریں ہی تو ہیں۔
1947 کی مار کاٹ بڑی بوڑھیوں کو 57کے غدر اور جلیانوالہ والا باغ کے خون خرابے کی یاد دلاتی ہیں۔
’ اچھی آزادی ہے، اگر اتنی موتوں کے بعد مل رہی ہےتو اس سے اچھی تو غلامی تھی۔‘
یہاں شہنام عرف شہنو اپنی کہانی سنا رہا ہے، ماں کا کردار دونوں ناولوں میں بڑا حساس لیکن علم و آگہی کا مرکز بھی ہے۔ شہنو کا بچپن صوفیہ، پنّو اور باسکوپ والی ریحانہ آنٹی کے آنگن میں سائیکل دوڑاتے یا اندر سبھا کا ناٹک دیکھتے گزرا۔
آخری بار مرنے سے پہلے کئی بار مرنا پڑتا ہے جیسے عزت خالہ، علن ماموں کے لکیر کے اس پار جانے پر ماں اور صوفیہ کے جانے پر شہنو کو مرنا پڑا تھا۔
پیاروں کو کہیں موت نگل لیتی ہے تو کہیں ہجرت ….. لیکن کہانی میں شہلا کی صورت میں امید پھر سے
انگڑائی لیتی ہے….ایک مجلس والا دوسری میلاد والی۔
حیدر گنج کی شہلا جس کا گھر بک چکا ہے۔
’ ایک آدھ اینٹ پتھر کی نشانی رہنے دینی چاہیے کہ مکین کبھی نہ کبھی اپنے پرانے گھر ضرور آتا ہے۔‘ ناول کا پلاٹ مرکزی کردار شہلا سے نگینے کی طرح جڑا ہے۔ ’عورت میں ارادے کی طاقت مرد سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔‘ شہلا کی زندگی اور ملک میں رونما ہونے والے حالات کو لکھاری نے آپس میں ایسے نتھی کیا ہے کہ کئی بار میکسم گورکی کی ماں یا میری یونیورسٹیاں یاد آجاتی ہیں۔ ظلم کو روکتے روکتے ہم خود ظلم کرنے لگتے ہیں۔
شہلا کے زبانی یونیورسٹی میں ہونے والے حالات نے مجھے قرتالعین حیدر کی آخری شب کے ہمسفر کی بھی یاد دلا دی، کہ جہاں بولنے کی آزادی سلب کر لی جائے وہاں دم گھٹنے لگتا ہے۔
مصنف نے لکیر کے دونوں جانب ترتیب وار تباہیوں اور بربادیوں کی داستان رقم کی ہے جہاں انسانوں کو پہلے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، پھر فرقوں میں بانٹا گیا اور پھر زبان کے اختلافات میں الگ الگ کیا گیا اور اس سارے کھیل میں انسانیت کا بے دریغ قتل ہوا۔
انیس اشفاق نے ایک ایک واقعہ کو ناول میں بڑی سادگی سے پرویا ہے چاہے وہ لکیر کے اُس پار گاندھی جی کا قتل ہو یا اندرا گاندھی کی ایمرجنسی یا موت …. یا سکھوں کا قتل عام ہو، لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات ہوں، ہندو انتہا پسندوں کی گجرات میں قتل و غارت گری ہو یا بابری مسجد کا شہید کیا جانا، وہیں لکیر کے اِس پار کبھی ترقی کے بودے خواب دکھا کر یا مذہب کا چولا پہنا کر مارشل لاؤں کو عوام پر تھوپنا ہو، یا بے راہ روی کا واویلا مچا کر مذہبی جنونیت کو ہوا دینا ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ماورائے عدالتی قتل کی روداد ہو، یا 80 کی دہائی میں لسانی فسادات کے خونی قصے ہوں،
موت بار بار ہماری نظروں کے سامنے نئی اشکال بدل کر آتی ہے۔
تمام واقعات ناول میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ قاری خود بخود ان تمام حادثات کے پیچھے اصل حقائق جاننے کے لیے خود کو تاریخ کے پنّوں میں گم کر لیتا ہے۔
جہاں ناول تاریخی واقعات کا احاطہ بڑے غیر محسوس طور پر کرتا ہے وہیں بٹوارے کے بعد عام لوگوں پر بیتے مظالم کو بھی سہل انداز سے عیاں کرتا ہے۔
چاہے وہ بٹوارے کے نتیجے میں ذہنی توازن کھو بیٹھنے والے دیوانے ہوں یا شہلا کی ڈری سہمی رشتہ دار خواتین، شہنو کے لڑتے جھگڑتے میاں بیوی مالک مکان ہوں یا شہلا کی دوست شہناز اور اس کے بوڑھے والدین، ناول میں جہاں ایک سیاسی جماعت مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کی تیاریوں میں ہے تو وہیں مسز بینر جی جیسے انسان دوست بھی امید کی شمع جلائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
دُکھیارے میں مصنف نے ایک خاندان کے شیرازہ بکھرنے کو قلم بند کیا ہے تو ’ ہیچ ‘ میں جنگ و جدل کی سفاکی، بٹوارے کے المیے، ہجرت کی دہائی ہے۔ سماج اور سیاست میں مذہبیت، لسانیت اور فرقہ واریت کے موضوع کو بڑی سہولت اور ایمانداری سے قاری کے سامنے کھول کر پیش کر دیا ہے۔
ناول نگار دونوں ناولوں میں قاری کا ہاتھ پکڑ کر ہر گزرے سانحے کی پوری تفصیل دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ انیس اشفاق صاحب کا اسلوب بے حد سادہ ہے، اس میں لفاظی ہے اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا فلسفہ…… اور یہی ان ناولوں کی خوبی ہےکہ ’آشوب میں نہیں، آشوب گزر جانے کے بعد اچھی تحریر سامنے آتی ہے۔‘
ادارے کا کالم نگار کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔