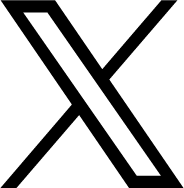ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم طائی نے جب ایک شہر فسوں دیکھا تو اس کے دل میں یہ آرزو انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ میں جب سعودی عرب سے لوٹا تو کچھ ایسی ہی خواہش میرے دل میں بھی تھی کہ اللہ بار بار اس دیار میں لے جائے اور حرمین شریفین کی زیارت سے سرفراز کرے۔ یہ واقعہ 1994ء کا ہے۔ ٹھیک 30 برس کے بعد جب میں سرزمین حرمین سے لوٹا ہوں تو میرے جذبات بالکل یہی ہیں لیکن ذرا سے فرق کے ساتھ۔
اس پاک دیار میں بار بار جانے کی آرزو کا سبب تو وہ کشش ہے جس سے ہر مسلمان کا دل معمور ہے۔ مجھے بھی استثنا نہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس دل نے چوں کہ جذباتی مزاج پایا ہے، اس لیے آرزو کچھ زیادہ منھ زور بلکہ شدید ہے، لیکن اس بار صورت حال میں ذرا فرق بھی ہے اور اس فرق کا تعلق ہے اس تہذیبی بانکپن سے جس نے مجھے تقریباً مسحور کر دیا۔ اس سحر کو سمجھنے کے لیے ایک سوال کا جواب ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کا سعودی عرب کہاں کھڑا ہے؟
یہ سوال اتنا سادہ اور آسان نہیں کہ جتنے منھ سے اتنی ہی باتیں، لیکن آپ اگر اکیسویں صدی کے پہلے ربعے میں کھڑے ہو کر ایک نگاہ دنیا پر ڈالیں تو شاید درست جواب تک پہنچ پائیں۔
کیا اکیسویں صدی کی دنیا اور اس کی طاقتیں ایمان دار ہو گئی ہیں اور اب انہوں نے فیصلے انصاف کے ساتھ کرنے شروع کر دیے ہیں اور مظلوموں کو ان کا حق ملنے لگا ہے؟ ایسا ہوتا تو آج غزہ پر آتش و آہن کی جو بارش ہوئی ہے اور انسانیت کا جو لہو بہا ہے، نہ بہا ہوتا۔ فلسطین اور کشمیر آزاد ہو چکے ہوتے اور طالبان افغانستان کو پیچھے دھکیلنے کے بجائے اپنے عہد میں لاتے اور اپنے پڑوسیوں کا حق بخوشی ادا کرتے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس تاریکی سے روشنی کی جو کرن پھوٹی ہے، اس کے اجالے نے کہیں شعور کو مہمیز دی اور نئے حقائق کا خیر مقدم ہوا ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ باقی دنیا اس سے پیچھے بلکہ کہیں پیچھے ہے۔ نظریاتی معاملے میں بھی اور تہذیبی اعتبار سے بھی۔
عالم اسلام چند برس پہلے تک وہیں کھڑا تھا جہاں 1857ء میں برصغیر کے مسلمان کھڑے تھے یعنی یا تو نئی تہذیب اور نئے حقائق کے سامنے سر جھکا دیا جائے یا اس سے ٹکرا کر سر پھوڑ لیا جائے۔ اسامہ بن لادن جیسا مزاج ہو یا نائن الیون کا حادثہ، یہ سب اسی ذہن کا نتیجہ ہے۔ برصغیر میں بیداری 1857ء کے بعد آئی۔ نائن الیون کے بعد مسلم دنیا میں بھی بیداری آئی جس کی ابتدائی کرنیں سعودی عرب پر پڑیں، آج جہاں چکا چوند ہے۔
تبدیلی کی تفصیلات طویل ہیں اور کالم کا دامن مختصر، اس لیے مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج اگر مسلمانوں کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ عسکریت اور جہاد کی پرائیوٹائزیشن ہلاکت خیز ہے تو روشنی کی یہ کرن بھی اسی ارض پاک سے پھوٹی ہے۔ اس خیال یا نظریے میں اتنی پاکیزگی اور سچائی ہے کہ صرف اس کی فہم کے پھیل جانے سے ہی مسلمانوں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ نظریہ صرف ہتھیار اور توپ و تفنگ کی دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا تعلق علم، ترقی اور بیداری سے بھی ہے۔ بیداری کی اسی لہر کی برکت آج اس دیار میں دکھائی دیتی ہے۔
1994ء کی بات ہے، ہم لوگ جدے میں پھنس گئے۔ ہم سعودی وزارت اطلاعات و نشریات کے مہمان تھے۔ ہم نے یہاں حج کے دنوں میں روزنامہ ’ریاض‘ کے زیر اہتمام پورے دو ماہ تک اردو اخبار شائع کیا تھا۔ اپنی ذمے داری نبھانے کے بعد عمرے کی نعمت سے سرفراز ہوئے تو واپس روانہ ہو گئے، لیکن جدہ ایئرپورٹ پر ہونے والے ایک اعلان نے ہمارے کس بل نکال دیے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ السید اطہر ہاشمی اور السید فاروق عادل وغیرہ وغیرہ کو خبر ہو کہ وہ پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ فلاں دفتر میں حاضر ہوں۔ حاضر ہوئے تو جس زبان میں مدعا بیان کر سکتے تھے، کیا لیکن افسر اعلیٰ نے بیزاری کے ساتھ کہا:
’تكلم عربي أو روح‘ یعنی عربی میں بات کر سکتے ہو تو کرو ورنہ جان چھوڑو۔ ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس واقعے کی یاد اب بھی تازہ تھی، لیکن اس بار تو ہمارا واسطہ کسی اور سعودی عرب سے پڑا۔ امیگریشن کے بعد شاید ہم حج ٹرمینل میں پہنچے اور اس خوف کے ساتھ پہنچے کہ جانے اگلا مرحلہ کیسے طے ہو گا، کوئی بات سنے گا بھی کہ نہیں اور سنے گا تو سمجھے گا اور جواب بھی دے گا یا اس افسر اعلیٰ کی طرح شٹ اپ کہے گا۔ بیم و رجا کے اسی عالم میں بیٹھنے کی جگہ تلاش کی لیکن اس سے پہلے ہی ایک شائستہ نوجوان نے خود مجھ تک پہنچ کر رواں دواں انگریزی میں ویزا دیکھنے کی خواہش کی، پھر اشارے سے بتایا کہ اس بہن سے بات کیجیے۔ یہاں ایک اور حیرت منتظر تھی۔ 1994ء کے سعودی عرب کو جاننے والے کے لیے تو بہن سے بات کرنا ہی بڑی ہمت کی بات تھی۔ بس خاموش جا کھڑا ہوا اور بہن نے از خود کاغذ دیکھ کر بتا دیا کہ یا اخی! بس نمبر 18۔
’یا الٰہی! یہ خواب ہے کہ حقیقت؟‘
میں ابھی اسی حیرت میں مبتلا تھا کہ ایک نوجوان نے خود پہنچ کر ہمارے فون میں سعودی سم انسرٹ کر کے ہمیں بہت سی مشکلات سے نجات دلا دی اور ہم میاں بیوی بس میں جا بیٹھے۔ بس میں بیٹھ کر گزشتہ 15,20 منٹ کے واقعات کو سمجھنے کی فرصت ملی تو سمجھ میں آیا کہ یہ مسافر تو 30 برس پہلے کے سعودی عرب کے بھلیکے میں تھا، آج کا سعودی عرب تو بالکل مختلف ہے، پروفیشنل ، کوآپریٹو، کشادہ اور خوش گوار۔
بات بدلے ہوئے خوش گوار رویوں تک محدود نہیں ہے۔ اس کے مظاہر زندگی کے ہر شعبے میں دکھائی دیتے ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر انتظام مملکت تک۔ ہمارے یہاں یہ کام پولیس کیا کرتی ہے اور سعودی عرب میں شرطہ۔ جدید معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ حسن انتظام تو دکھائی دے لیکن منتظم کی رونمائی کم سے کم ہو۔ ہمارے یہاں منتظم کا جلوہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ انسان سے لے کر مشین تک سب کچھ خودکار ہو گیا ہے۔ مسافر اور ہم سفر بیت الحرام سے نکلے تاکہ سوق خلیل کے خوش نما، خوش گوار ماحول میں کچھ لذت کام و دہن سے کام لیں اور ٹانگوں کے سکون کے لیے تھوڑا سا مشینی مساج کرا لیا جائے۔ یہ احرام پوش مسافروں کی بے خیالی تھی یا اجنبیت کی گھبراہٹ کہ سڑک کے وسط تک پہنچتے پہنچتے کئی گاڑیوں کو بریک لگ گئے۔ مسافروں نے یہ سوچتے ہوئے سوق خلیل کی سیڑھیوں پر قدم رکھے کہ تہذیبی بانکپن کے لیے شاید اسی قسم کی اخلاقی اور تہذیبی پیش رفت ضروری ہوتی ہو؟
نہیں معلوم یہ کوئی اتفاق ہے یا قدرت کا کوئی انتظام کہ سعودی عرب میں میرا پالا ہندوستانی مسلمانوں سے ضرور پڑتا ہے۔ 1994ء میں یہاں آنے سے قبل قرۃ العین حیدر کے ناول ’آگ کا دریا‘ کا مطالعہ کوئی دسویں بارہویں بار کیا تھا۔ یہ ناول ایک فسوں ہے اور کچھ جادو اس کے لکھنے والی میں ہے۔ اس بی بی کے بڑے شعوری مسلمان تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کی فکری پیش رفت میں ان کے والد ہی نہیں والدہ کا کردار بھی بہت اہم تھا، لیکن یہ خاتون اس الجھن میں مبتلا تھیں کہ آخر پاکستان اور ہندوستان کی تہذیب میں جوہری فرق ہی کیا ہے؟ اُس سفر میں میری ملاقات حبیب صاحب سے ہوئی۔ یہ ملاقات کئی اعتبار سے دل چسپ تھی۔ روزنامہ ’ریاض‘ کے ہمارے تخلیق کردہ اردو نیوز روم میں ایک روز جب ہم تمام خبروں سے نمٹ کر چائے کی چسکی لینے لگے تو انہوں نے کہا:
’میں سوچتا ہوں، آگ کا دریا مکمل کر دوں۔ ‘
’آگ کا دریا نامکمل ہے کیا؟‘
میرے حیرت بھرے سوال پر حبیب صاحب کہنے لگے کہ قرۃ العین حیدر کے حیرت بھرے سوالوں کا جواب ملنے تک نامکمل ہی ہے۔ مطلب یہ کہ بابری مسجد کی شہادت نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں اور میں اس ناول کا آخری باب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نہیں معلوم حبیب صاحب اب کہاں ہیں۔ کاش کہ حالیہ سفر میں ان سے ملاقات ہوئی ہوتی۔ ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی البتہ اس کی کمی پوری ہو گئی۔
حرم سے نکلنے کے بعد ہم بس میں جا بیٹھے جیسے ہی بس ذرا سا کھنگار کر آگے بڑھی، آخری نشست پر بیٹھے لوگوں کی گفتگو شروع ہو گئی۔
’آپ کہاں سے ہو بھائی؟‘
’جے پور سے اور یہ بھائی ہے اودے پور سے۔‘
’پر تو کہاں سے ہے؟‘
’میں جی یوپی سے۔ اب تم پچھو گے یوپی سے کہاں سے تو بھائی میں مجفظر (مظفر) نگر کا ہوں۔‘
’کیا اللہ کی سان ( شان) ہے یہاں۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ جی بھر کے عبادت ہو رئی یہاں تو۔ کس کس رنگ کا مسلمان یہاں دیکھنے کو مل را۔‘
’ہاں، ٹھیک کہوے ہے بھائی۔ وے ہمارے بھائی پاکستان بنڑا ( بنا) کے اچھے رہ گئے۔‘
’ ہماری تو دس منٹ کی نماز بھی انھیں کَھلے ہے۔‘
ہاں بھائی، خود تو پورے دس دن سب کچھ بند کر دیوے ہیں۔ سکول تک بند کر دیوے ہیں۔‘
’بس جی، یہی ہماری قسمت ہے اب تو‘
وہ خاموش ہوا تو مسافر نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور سوال کیا کہ یہ پورے دس دن ہندوستان بند کیوں رہتا ہے؟
ان کا تیوہار ہوتا ہے بھائی، ’کاوڑا‘ ۔ ان دنوں وے گنگا سے پانی لاتے ہیں کاندھوں پر رکھ رکھ کر۔ یہ کہہ کر وہ لحظہ خاموش ہوا پھر کہا کہ نیٹ پہ دیکھ لینا تفصیل مل جاوے گی۔
یوپی والا اپنی بات کہتا رہا، اسی دم دانائے راز نے سرگوشی کی،
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد
یہ تو ہوئی اقبال کے زمانے کی بات جب مولانا ابوالکلام اور حضرت مدنی کو ہندوستان میں آزادی دکھتی تھی۔ کاش یہ بزرگ سمجھ پاتے کہ 75 برس کے بعد ان کی اولادوں پر کیسا وقت آنے والا ہے۔
’اے ہے، کوئی اے سی ہی تیز کر دیو‘۔
یوپی والے کے پہلو میں بیٹھی بی بی گرمی سے گھبرا کر چلائیں۔ میرے خیال کو ایک بار پھر مہمیز لگی کہ بھارتی مسلمان ہوں، افغان طالبان ہوں یا کوئی اور سب گل محمد بنے کھڑے ہیں۔ زمین حرکت میں آئے یا نہ آئے، ان کے پائے ’استقلال‘ میں لغزش نہیں آتی۔ جب تک یہ نہیں بدلتے یعنی سعودی عرب کی طرح خود کو نہیں بدلتے، ان کی دنیا ہی نہیں قسمت بھی بدلنے والی نہیں۔
ادارے کا کالم نگار کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔