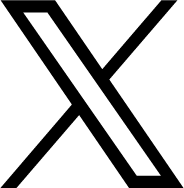وہ شاید دوپہر کا وقت تھا، میں اچھرہ مدرسہ والی گلی سے نکلا اور 5 ایک ذیل دار پارک پہنچا۔ گیٹ کھلا، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں گھستے چلے آتے ہو؟ ڈرائیو وے سے ہوتے ہوئے نہایت احتیاط سے برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگی۔ مرکزی پھاٹک کی دائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا، جیسے اجنبی کیا کرتے ہیں، گردن ذرا سی اندر ڈال کر جھانکا۔ چند سوالیہ نگاہیں اجنبی کی طرف اٹھیں تو اس نے لہجے کو ذرا سا پر اعتماد بناتے ہوئے کہا:
‘ مولانا سے ملنا ہے’.
‘ مولانا سے ملنا ہے؟’.
سوالیہ نگاہوں میں تعجب بلکہ یو ں کہیے کہ تعجب سے بھی بڑھ کر کچھ اس قسم کا تاثر تھا کہ چہ پدی چہ پدی کا شوربہ، 13-14 برس کے لڑکے کا کیا کام کہ وہ مولانا سے ملے؟ سرگودھا جیسے نیم دیہی، نیم قصباتی شہر سے آنے والے نے سیدھا کھڑے ہو کر اس چیلنج کو قبول کیا اور آواز کو بھاری بناتے ہوئے ملنے کی وجہ بھی بتا دی کہ آٹو گراف لینے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:سعودی عرب: بار بار دیکھنے کی ہوس
حیرت کرنے والوں کو اس بات میں تھوڑی معقولیت دکھائی دی۔ ایک صاحب نے نرمی کے ساتھ کہا :
‘البم دے جایے، کل اسی وقت آ کر لے جایے گا’.
جواب معقول تھا اور ایک دیرینہ خواہش بھی یقینی طور پر پوری ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں کسی قدر سوچ میں پڑ گیا۔
سوالیہ نگاہوں کی تاب کا مسئلہ اپنی جگہ تھا، لیکن تازہ تازہ میٹرک پاس کرنے والے لڑکے کے مطالعے میں اس وقت تک جو کچھ آیا تھا، اس کے باعث وہ محرومی کے ایک گہرے احساس کا شکار تھا۔ اس زمانے میں نصابی یا غیر نصابی جو کتاب بھی اس نے پڑھیں، اس کے مطالعے سے اس کا یہ احساس قوی ہوا کہ بڑے لوگوں کا زمانہ تو ہم لوگوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیت گیا۔
یہ بھی پڑھیں:اسرائیل سے ملنے والی تازہ گواہی
قائد اعظم علیہ رحمہ، عظمت مآب علامہ اقبال، سرسید احمد خان، علی برادران، غرض عظمت کے جس مینار کا بھی ذکر ہوتا، وہ تاریخ کے اوراق پر اپنا دائمی نقش ثبت کرنے کے بعد میری دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ خلد آشیانی ابا جی اور ان کے دیرینہ دوست مولانا حکیم عبدالرحمٰن ہاشمی کی صحبت کا فیض ہی رہا ہو گا کہ محرومی کے احساس میں کسی قدر کمی واقع ہوئی۔ ان بزرگوں کی محفلوں میں، تاریخ اور مذہب سے لے کر حالات حاضرہ تک، بہت کچھ زیر بحث آتا۔ قبلہ ہاشمی صاحب کے ہاں کی محفلوں کی خوبی تھی کہ ان میں ہم عصروں کو نمایاں جگہ ملتی تو نوجوان اور بچے محروم نہ رہتے۔ ترتیب بڑی دل چسپ تھی، سب سے آگے بزرگوں کے قریب بیٹھنے کے شوقین بچے، ان کے بعد بزرگ اور بزرگوں کے بعد نوجوان۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے عہد کی قدآور شخصیت جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی سب سے پہلے وہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ان ہی پاکیزہ محافل کا فیض تھا کہ اُن بزرگوں کی اولادوں یعنی ہم لوگوں کو بعض اوقات ایسی ایسی باتیں معلوم ہوتیں، بڑے ہو کر حیرت ہوئی کہ بہت سے نام ور نہیں جانتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان بزرگوں کی گفتگو سے میرے علم میں یہ آیا ہوگا کہ ہمارا عہد کچھ ایسا بھی بد قسمت نہیں کہ اس میں مولانا مودودیؒ سانس لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں کا کہنا تھا کہ مولانا ہماری تہذیبی کشمکش کی تاریکی میں ان بزرگوں کی وہ روشن کڑی ہیں جنہوں نے مایوسی میں امید کا دیا روشن کیا اور الجھے ہوئے راستوں میں سے درست راستے کی نشان دہی کی۔
برصغیر کے مسلمانوں کا المیہ 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد دو چند ہوا۔ وہ انگریزی استعمار کی آمد کے بعد ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ انگریزی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ نجات کا راستہ جنگ میں ہے یا پُرامن سیاست میں؟ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں درست راستے کی نشان دہی کی اور بتایا کہ سلامتی کی راہ امپیریلزم سے نجات اور پارلیمانی سیاست میں ہے۔ یہی فکر تھی جس نے ہمیں پاکستان دیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ سوال ایک بار پوری طاقت کے ساتھ اُٹھ کھڑا ہوا کہ اسلام کا نظام سیاست و حکومت کیا ہے؟ مولانا مودودی نے ‘ خلافت و ملوکیت ‘ لکھ کر بتایا ہماری تاریخ کی ٹوٹی ہوئی کڑی کون سی ہے اور یہ کہ ہمیں کرنا کیا یے۔
یہی پس منظر تھا جس کے سبب میں نے شکر گزاری کے گہرے جذبے کے ساتھ ان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور بڑے احترام کے ساتھ عرض کی، اس عنایت پر میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا، لیکن یہ آٹو گراف لینے کا موقع مجھے خود ملا تو میری خوش نصیبی دوگنا ہو جائے گی، مجھے اپنے وقت کے ایک بڑے آدمی کو دیکھنے اور ایک حد تک ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ جو کوئی صاحب بھی تھے، میری بات سن کر سنجیدہ ہو گئے اور پہلے کی نسبت نہایت خلیق لہجے میں کہا:
‘ اگر آپ کو ان کے آٹو گراف میں دل چسپی ہے تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مولانا علیل ہیں، جوڑوں کے درد کے باعث ان کی سرگرمیاں معالجوں کی ہدایت کے مطابق نہایت نپی تلی اور منظم ہوتی ہیں، اس لیے ان سے آٹو گراف لینے کا ہم نے ایک نظام وضع کر رکھا ہے، اس کے تحت وہ کسی اضافی زحمت کے بغیر یہ کام کر سکیں گے۔ رہ گیا آپ کی ملاقات کا شوق تو اس کا حل یہ ہے کہ مولانا بیشتر نمازیں یہاں، انہوں نے سامنے لان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پڑھتے ہیں، آپ نماز یہاں پڑھیے اور مولانا کو دیکھ بھی لیجیے۔ اس واقعے سے اگلے 2-3 دن کے دوران میں؛ مَیں لاہور میں اپنے رشتے داروں کے یہاں رہا اور پابندی کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں اس لان میں پڑھیں۔
یہ بھی پڑھیں:ایک عجب شہر کی مختلف خوشبو
مولانا واکر کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے جالیوں والے کمرے سے نکلتے، پہلی صف میں انتہائی دائیں جانب بید سے بنی ہوئی لکڑی کی ایک نسبتاً آرام کرسی رکھی ہوتی، جس پر وہ بیٹھ جاتے تو امامت کرانے والے صاحب اقامت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرا دیتے۔ مولانا کا دھیرے دھیرے چل کر آنا مجھے یاد ہے، لیکن وہ برآمدے کی 2 یا 3 سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے کیسے تھے؟ یہ قطعاً ذہن میں نہیں۔ یوں میں نے اپنے لڑکپن یا آغاز شباب میں مولانا کو دیکھا اور ان کے ساتھ کئی نمازیں بھی ادا کیں۔
مولانا کو یوں قریب سے دیکھا تو ایک اور دل پذیر منظر یاد آ گیا، جس کے اثرات میں آج بھی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں۔
میرے والد اپنے عہد کے ایک بڑے طبیب اور حکیم تھے، جنہوں اسپرین اور اسپرو کے عہد میں دیسی جڑی بوٹیوں سے کیفاکین کے نام سے ایسی دوا ایجاد کی تھی جو اپنے وقت کی ان جدید ترین دواؤں کی طرح چند منٹ میں پسینہ لا کر بخار سے نجات دلا دیتی تھی۔ دوا تو انہوں نے ایجاد کرلی لیکن مارکیٹنگ کا فن شاید ایجاد سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے وہ اپنی ایجاد کردہ دواؤں کی کامیابی سے فروخت کا کوئی نظام نہ بنا سکے۔ اس پر مستزاد ان کا عارضہ قلب، جس کی وجہ سے ان کی توانائیاں ماند پڑ چکی تھیں۔ اس مشکل میں ان کے دوست مولانا حکیم عبدالرحمٰن ہاشمی بروئے کار آئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی طرح جماعت اسلامی کے اراکین کی فہرست حاصل کرلیں، ان میں حکیم اور معالجین کی بڑی تعداد ہوگی۔ ان لوگوں سے کسی طرح رابطہ کر کے ان دواؤں کی فروخت کا کوئی قابل اعتماد نظام بن سکتا ہے۔
یہ بات ان کے دل کو لگی اور انہوں نے، جب مَیں شاید آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا، اپنے ایک سیلز مینیجر محمد اشرف شاہین کے ساتھ مجھے لاہور بھیج دیا۔
جس وقت ہم منصورہ پہنچے، دیکھا کہ ابا جی کے کچھ دوست چوہدری ظفر اللہ خاں، ملک علی محمد فاروق اور کچھ دیگر بزرگ وہاں سے نکل رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد ان بزرگوں نے کہا کہ یہ کام جس سے تم لوگ آئے ہو، وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج کا دن ایک یاد گار دن ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ یوں میں زندگی میں پہلی بار نیو کیمپس پہنچا، جس کے فیصل ہال میں جوق در جوق لوگ داخل ہوتے اور جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اشرف اور مجھے ہال کی پچھلی کرسیوں کے پیچھے سیڑھیوں والی نشستوں پر جگہ ملی۔ ذرا سی دیر میں ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ لوگ نہایت خاموشی اور احترام سے بیٹھے تھے، اگرچہ اسٹیج ابھی خالی تھا۔
یہ بھی پڑھیں:جب مشرف کے اعصاب چٹخے
کچھ ہی دیر میں تھوڑی سی ہل چل ہوئی، اسی دوران میں چند لوگوں کے جلو میں مولانا جو آف وائٹ شیروانی میں ملبوس تھے، بائیں طرف سے اسٹیج پر پہنچ کر مرکزی نشست پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کی صرف 3 باتیں مجھے یاد ہیں۔ تقریب کے میزبان جو پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر عبد الشکور تھے ( جو بعد میں الخدمت کے صدر کی حیثیت سے معروف ہوئے)، انہوں نے انتہائی پُرجوش خیرمقدمی تقریر کی اور کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ مولانا کو جامعہ میں لاؤں گا، آج میں سرخ رو ہوا۔
دوسری بات جو مجھے یاد ہے، اس کا تعلق مولانا کےانداز گفتگو اور اس پر اردو کے غلبہ سے ہے، انہوں نے عام روایت کے مطابق یونیورسٹی کی یونین کا ذکر کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس یونین کہنے کے بہ جائے انجمن اتحاد طلبہ کے الفاظ سے مخاطب کرنا مناسب خیال کیا۔
تیسری بات جو مجھے یاد ہے، یہ ہے کہ ہال میں خاموشی تو پہلے بھی تھی لیکن مولانا کی آمد کے بعد تو واقعی سمجھ میں آ گیا کہ سوئی گرنے کی آواز آنے کا محاورہ کیوں بنا ہو گا۔
تیسری یاد کا تعلق اسی خاموشی میں ابھرنے والی ایک آواز سے تھا۔ ہال سے دھیمی سی ایک آواز بلند ہوئی۔ کہنے والے نے کیا کہا ہوگا، اس کا اندازہ یوں ہوا کہ جواباً سوالیہ انداز میں مولانا نے ان ہی کی بات دہرائی:
” آواز نہیں آ رہی؟”.
بعد میں مولانا کی آواز لوگوں تک کیسے پہنچی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مولانا کے لہجے کا اتار چڑھاؤ مجھے کسی انتہائی تازہ بات کی طرح یاد ہے۔ ہمارے والدین ہوں یا ان کے بھی بڑے، وہ جب اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کے ساتھ بے انتہائی پیار اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی شفقت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں ایسی ہی حلاوت، بزرگی، حلم، محبت اور شفقت کا رچاؤ ہوتا ہے۔ جامعہ پنجاب میں مولانا نے اس روز وہ معروف خطاب کیا جو کتابی شکل میں ‘ سیرت کا پیغام’ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اس خطاب کی شہرت اس زمانے میں بھی بہت تھی اور آج بھی اسے ایک وقیع علمی حوالے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے مولانا کا وہی ایک سوالیہ جملہ یاد ہے:
‘ آواز نہیں آ رہی’.
میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کے انداز، ان کے لہجے اور لہجے کی شیریں لہروں میں تیرتی ہوئی شفقت نے میری جو تہذیبی تربیت کی، وہ بڑی بڑی کتابوں اور بڑے بڑے وعظوں پر بھاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں:پاکستان کا قومی ترانہ، معیار، انتخاب اور تنازعات
بعد کے زمانوں میں جب میں کالج کا طالب علم تھا، مولانا کو 2 بار مزید دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ جنرل ضیا کے مارشل لا کا اولین زمانہ تھا، ہم لوگ اپنے کالج کی طلبہ یونین کا انتخاب جیت کر لاہور گئے ہوئے تھے، تاکہ ہفتہ طلبہ کے لیے کچھ اہم شخصیات کو مدعو کیا جاسکے۔
ہمارے نہایت ہی پیارے استاد پروفیسر ارشاد حسین نقوی صاحب کی خواہش تھی کہ کمال ہو جائے، اگر تم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو مدعو کر لاؤ۔ اس مقصد کے لیے ہم لاہور گئے جہاں سرگودھا سے تعلق رکھنے والے پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم منور اقبال احمد گوندل کے ساتھ لاہور کی خوب سیر کی۔ اسی بھاگ دوڑ میں منور ہمیں ایک روز اچھرے لے گئے۔
‘ کیا مولانا مودودی کو مدعو کریں گے؟’.
میں نے سوال کیا تو منور مسکرائے اور کہا کہ دیکھو تو سہی۔ ہم لوگ مولانا کے ہاں پہنچے تو ابھی اکا دکا لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ منور صاحب نے وہاں رکھی مولانا کی کرسی کو ایک نظر دیکھا، مسکرائے اور میرا ہاتھ پکڑ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ مولانا اپنے واکر کا سہارا لیتے ہوئے نکلے۔ وہ کرسی پر بیٹھے تو ہم دونوں عین ان کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے جیسے خاک دانی کے آرزو مند مریدین مرشد کامل کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ واقعہ میں نے گھر پہنچ کر امی کو سنایا تو وہ بے اختیار مسکرائیں۔ کہا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تم شیر خوار تھے، سعودی حکومت کی دعوت پر مولانا نے غلاف کعبہ تیار کرایا۔ پاکستان کے لیے یہ بڑے اعزاز اور سعادت کی بات تھی، عوام چاہتے تھے کہ انہیں بھی اس کی زیارت کا موقع ملے، چنانچہ جہاں جہاں ٹرین رکی، عوام سیاسی و مسلکی وابستگی سے بالاتر ہو کر زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ٹرین رکی تو مولانا اس سے اترے، استقبال کے لیے جمع لوگوں سے مصافحہ کیا۔ امی بتاتی ہیں کہ اس ہجوم میں بے شمار دوسرے لوگوں کے علاوہ وہ خود اور میرے اباجی بھی تھے، جنہوں نے ایک شیر خوار بچے کو بھی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مولانا مودودی نے نہایت شفقت سے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
‘ جانتے ہو، وہ بچہ کون تھا؟’
‘ کون تھا؟’
میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں امی نے جو بات کہی، اسے سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ بات یاد آتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا واقعی میں اتنا خوش قسمت ہوں؟
ادارے کا کالم نگار کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔