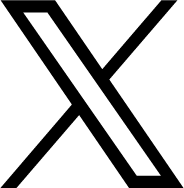محمد سعید گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ سعادت حسن منٹو ان کی علمی تگ و تاز کا بنیادی حوالہ ہیں۔ انہوں نے 15 سال پہلے منٹو کی 62 متفرق تحریریں اخبارات و رسائل کے بندی خانے سے نکال کر ’نوادرات منٹو‘ کے عنوان سے مرتب کی تھیں۔ وہ ان تحریروں کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں:
’ان کے ذریعے سے منٹو کے فکری، فنی اور ذہنی عمل و ارتقا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے کیونکہ یہ تحریریں منٹو کی پوری ادبی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں‘۔
لیاقت علی خان کی برسی پر ’نوادرات منٹو‘ کا خیال یوں آیا کہ اس میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم کے قتل سے متعلق منٹو کا نادر مضمون ’قتل، قاتل اور مقتول، ایک فریم میں‘ شامل ہے جس کے بارے میں محمد سعید نے یہ جچی تلی رائے دی ہے :
’لیاقت علی خان کے قتل سے متعلق کسی ادیب کے قلم سے پہلا مضمون ہے۔ اس وقت کی عام اخباری خبروں اور افواہوں سے ہٹ کر اس میں منٹو بڑے تفتیشی انداز سے لیاقت علی خان کا قتل زیر بحث لائے ہیں جو ان کے گہرے سیاسی، سماجی اور تنقیدی شعور کا غماز ہے۔ اس مضمون میں منٹو کا قلم وہ آنکھ بن گیا ہے جو قتل سے پہلے، موقع واردات اور چند دن بعد کی حکومتی سرگرمیوں کے بڑے واضح مناظر دیکھ اور دکھا رہا ہے۔ وہ زبان بن گیا ہے جو اس قتل سے متعلق ہر شخص خصوصاً حکومتی عہدیدران سے سوال کرتا ہے‘۔
یہ بھی پڑھیں: پاکستان ٹیم پر انگریز امپائروں کی ’مہربانیاں‘
ہر بڑا لکھنے والا کچھ بڑے سوال اٹھاتا ہے۔ اردو کے ادیبوں میں منٹو سے بڑھ کر یہ فرض کسی نے ادا نہیں کیا۔ منٹو نے فکشن کے ساتھ ساتھ نان فکشن میں بھی سوالات قائم کیے ہیں، اس لیے ’پورا منٹو‘ سمجھنے کے لیے ان کے خاکوں اور مضامین کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔
گارسیا مارکیز کے ناول ’ایک پیش گفتہ موت کی روداد‘ میں ایک کیریکٹر کہتا ہے:
’آدمی کو ہمیشہ مرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے‘۔
منٹو کی فکشن میں سربلندی کا سبب یہ بھی ہے کہ ان کی ہمدردی ہمیشہ مرنے والوں سے رہی اور یہ بات لیاقت علی خان پر ان کے مضمون میں بھی نظر آتی ہے۔
منٹو کو لیاقت علی خان کے قتل پر تشویش اس لیے ہے کہ وہ سازش سے جرم کے تال میل کی خوب خبر رکھتے تھے۔ واقعات کی کڑی سے کڑی ملا کر وہ واردات کی تفہیم آسان بناتے ہیں۔ اشاروں کنایوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور یہی تخلیق کار کی انفرادیت ہوتی ہے۔ وہ مقالہ نہیں لکھتا بلکہ احساس اور مشاہدے کو یکجا کر کے قاری کے دل و دماغ دونوں کو سوچنے اور محسوس کرنے ہر اکساتا ہے۔
بڑے تخلیق کار کی ایک تعریف محمد سلیم الرحمٰن نے کی ہوئی ہے اس پر بھی منٹو پورے اترتے ہیں:
’بڑے اور کھرے تخلیق کار کا ہاتھ اپنے معاشرے کی نبض پر ہوتا ہے اور وہ اشاروں اشاروں میں موجودہ اور آئندہ لاحق ہونے والی خرابیوں کی خبر دے سکتا ہے۔ وہ کھل کر بات نہیں کرتا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ نسخے نہیں لکھتا۔ یہ کام سیاسی اور نظریاتی کیمیا گروں یا بازی گروں کا ہے‘۔
منٹو کی تحریریں اپنی تخلیقی ہنر مندی کے باعث حسبِ حال رہی ہیں لیکن اس میں کچھ شائبہ ہمارے حالات اور سوچ کی یکسانیت کا بھی ہے۔
مزید پڑھیے: ریٹائرمنٹ اور توسیع کے درمیان جھولتی عدالتی تاریخ
منٹو نے مضمون میں راولپنڈی کے انگریز ڈپٹی کمشنر کے طرزِ عمل پر بات کی ہے جس سے میرا ذہن پنڈی وال بھیشم ساہنی کے ناول ’تمس‘ کی طرف گیا جس میں راولپنڈی کا گورا ڈپٹی کمشنر رچرڈ تقسیم کے ہنگام فسادات روکنے سے پہلو تہی کرتا ہے اور شہر میں مذہبی منافرت کی آگ پھیلنے دیتا ہے۔
یہ ڈپٹی کمشنر ہندوستانی تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہاں کے فنون لطیفہ کا دلدادہ ہے لیکن اسے برطانوی سامراج کے گماشتے کی جون میں آتے دیر نہیں لگتی۔ بھیشم ساہنی نے گورے ڈپٹی کمشنر کے بارے میں جو بات لکھی وہ ان کے بعد کالے ڈپٹی کمشنروں پر بھی فٹ بیٹھتی ہے۔الا ماشاءاللہ ۔ وہ لکھتے ہیں:
’یہ تصور کہ ہمارے عمل کو ہمارے افکار کا آئینہ دار ہونا چاہیے ایک ایسا بھونڈا آدرش واد ہے جس سے ہر شخص سول سروس میں پہنچتے ہی اپنا دامن چھڑا لیتا ہے‘۔
ڈپٹی کمشنر کی بیوی لیزا میاں کا ایجنڈا بھانپ لیتی ہے:
’بہت چالاک مت بنو رچرڈ! میں سب جانتی ہوں۔ ملک کے نام پر یہ لوگ تمھارے ساتھ لڑتے ہیں اور مذہب کے نام پر تم انہیں لڑاتے ہو‘۔
اس پر رچرڈ کا جواب برطانوی سامراج ہی نہیں ہمارے حکمرانوں کی فرسودہ سوچ کا بھی عکاس ہے:
’ڈارلنگ حکومت کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ رعایا میں کون سی باتیں مشترک ہیں۔ ان کی دلچسپی تو یہ دیکھنے میں ہوتی ہے کہ وہ کن کن باتوں میں ایک دوسرے سے الگ ہیں‘۔
فتنہ پرور حکومت ہو یا کوئی جتھہ، وہ کبھی لوگوں میں اشتراک کے نکتے نہیں تلاشے گا بلکہ اختلافی باتوں کو ہوا دینا ہی اس کا شعار ہو گا۔
مزید پڑھیں: شاعروں، ادیبوں کی پتھریاں اور درد کا سنگِ گراں
صاحبو! نہ جانے کیوں آج اصل موضوع کا سرا ہاتھ سے پھسل پھسل جاتا ہے لیکن شاید ادھر ادھر کے حوالے بھی اصل موضوع سے جڑتے ہیں۔ اور بات کچھ یوں بھی اس طرف نکل پڑی کہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کا قتل صرف ایک انسان کی رگ جاں پر وار نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے معاشرے کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی سازش ہوتی ہے۔
راولپنڈی میں لیاقت علی خان کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا دن دیہاڑے قتل بھی قومی یک جہتی کو تار تار کرنے کے لیے تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کی طرح 27 دسمبر 2007 کو بھی جائے وقوعہ سے ثبوت دھونے میں ’کوتاہی‘ نہیں کی گئی تھی۔ حبیب جالب کا مصرع یاد آتا ہے:
’کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں‘
منٹو نے لیاقت علی خان کے قتل پر مضمون میں پنجاب پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ جن جن پہلوؤں سے گرفت کی ہے وہ اب بھی ہمارے لیے اجنبی نہیں ۔ یہ ادارہ آج بھی اپنی روش پر قائم ہے۔
منٹو نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ سرحد کی حکومت نے پنجاب حکومت کو سید اکبر کے بارے میں اپنے شکوک سے آگاہ کیا تھا۔ یہ بات منٹو کے خیال میں بہت اہم تھی:
’پنجاب پولیس جو معمولی سے شبہ پر مچھروں اور مکھیوں کو بھی گرفتار کر لیا کرتی ہے اتنی اہم رپورٹ ملنے پر خاموش کیوں رہی ۔ اس نے قاتل سید اکبر کی جملہ نقل و حرکت پہ نگرانی کیوں نہ رکھی؟
معمولی سے معمولی سیاسی کارکن کی نقل و حرکت بھانپ بھانپ کر اور ماپ ماپ کر وہ اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا ہونے والا قاتل جس پر ایک عرصے سے شبہ تھا بڑے آرام سے ہزارہ سے نکلتا ہے۔ پولیس کو اپنی منزل اور اپنے جائے قیام کا بالکل صحیح پتا دیتا ہے اور 6 گز کے فاصلے پر بیٹھ کر ایسا نشانہ لگاتا ہے کہ پہلی گولی کام کر جاتی ہے‘۔
قاتل کے وزیر اعظم کے قریب پہنچ جانے سے سکیورٹی کی قلعی کھل جاتی ہے اور رہی سہی کسر سید اکبر کے موقعے پر قتل سے پوری ہو جاتی ہے۔
لیاقت علی خان کے گولی لگنے کے بعد پولیس کے ہوائی فائرنگ کرکے افراتفری پیدا کرنے اور ہجوم کے ہاتھوں قاتل کی درگت اور پھر اسے مارنے کی منٹو کو کوئی تک سمجھ نہیں آتی کہ اس سے پس پردہ کرداروں تک پہنچنے کی سب سے محکم بنیاد منہدم ہو گئی تھی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دولتانہ کے روایتی بیان سے منٹو کی تشفی نہیں ہوتی۔ منٹو سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
منٹو اس مضمون میں بڑے قرینے سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ادب میں آپ تخلیقی تجربے کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں لیکن روزانہ اخبار میں لامحالہ بہت سی باتوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اخبار کی پالیسی، ایڈیٹر اور مالک کی ترجیحات اس پر مستزاد ذمہ داروں کے تعین کی کوشش کے نتائج بھی کوئی معما نہیں۔ پھر جو گروہ وزیراعظم کے قتل میں ملوث ہو اس کی طاقت کا ٹھکانہ کیا ہو گا۔ بعد کے واقعات سے یہ ثابت بھی ہوا۔ صرف ایک مثال دیکھ لیجیے کہ تفتیش پر مامور اعلیٰ پولیس افسر اعتزاز الدین کے طیارے میں آگ بھڑکی جس میں صرف وہی نہیں لیاقت علی خان کے قتل کیس کے بارے میں تمام کاغذات بھی جل کر راکھ ہوگئے۔
یہ بھی پڑھیے: عدلیہ کی ’اصلاح‘ میں عجلت اور ماضی کے چند سبق
اس کیس سے متعلقہ کرداروں کے بارے میں حساسیت کا یہ عالم تھا کہ انسپکٹر محمد شاہ جو سید اکبر کی قتل کے جرم میں ملازمت سے برطرف ہوا تھا وہ بعد میں خود بھی قتل ہو گیا۔ خبر میں سید اکبر کے قتل کا حوالہ آجانے پر ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس تناظر میں منٹو کی بصیرت ہی نہیں جرات مندی کو بھی سلام کرنا بنتا ہے۔
منٹو نے یہ مضمون لیاقت علی خان کے سپردِ خاک ہونے کے چند دن بعد سپردِ قلم کیا تھا جب حقائق سرکاری چھلنی سے قطرہ قطرہ ٹپک رہے تھے اور ان کا مقصد سچ آشکار کرنا نہیں تھا بلکہ گرد اڑانا تھا لیکن کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے فن میں منٹو سے زیادہ کون مشاق ہوگا۔
منٹو نے سب سے زیادہ سید اکبر کے قتل کے مضمرات پر بات کی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی ردعمل کا نتیجہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی اسکیم تھی جس پر عمل درآمد ہوا۔ ہوائی فائرنگ سے پیدا ہونے والی بھگدڑ کو جہاں سید اکبر کو ٹھکانے لگانے کا بہانہ بنایا گیا وہیں ایسی صورت حال میں زخمی کو طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچانے میں تاخیر بھی ممکن ہوئی تاکہ اس کے جانبر ہونے کا امکان بھی ختم ہو جائے۔
منٹو کے خیال میں یہ جاننا پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کا وزیراعظم کیسے جان کی بازی ہارا اور ’اس کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ اگر کیے گئے تھے تو وہ کیوں ناکام ثابت ہوئے؟‘
پاکستانیوں کو آج تک اپنے وزرائے اعظم کے جان سے محروم ہونے کی اصل وجوہات پتا چلیں نہ ہی اقتدار سے محروم ہونے کی۔ اور بقول سراج اورنگ آبادی ’جو رہی سو بے خبری رہی‘۔
منٹو نے سید اکبر کے تذکرے پر مضمون ختم کیا ہے:
’سید اکبر نے خان لیاقت علی خان کو قتل کرکے پاکستان پر ایک شدید ضرب لگائی اور سید اکبر کو قتل کر کے ایک یا زائد آدمیوں نے اس کو اور اس کی شاخ کو بھی کاٹ دیا، جس کا سہارا لے کر اس نے یہ ضرب لگائی تھی‘۔
ادارے کا کالم نگار کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔